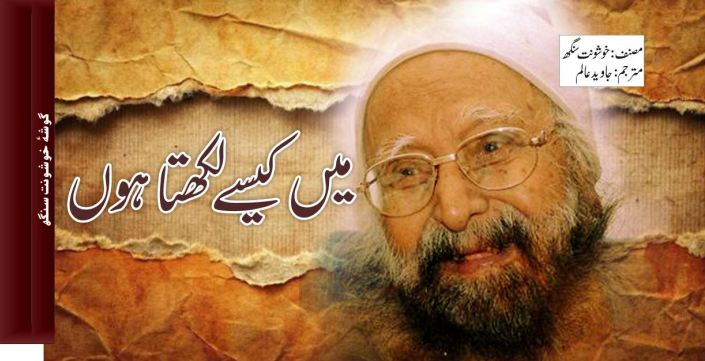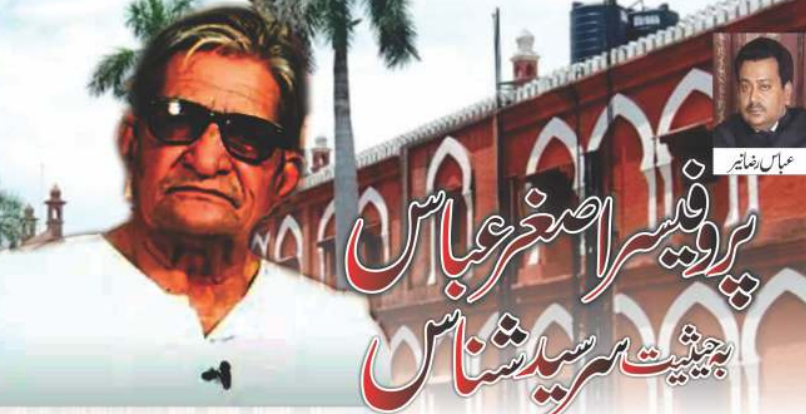اردودنیا،فروری 2026:
مجھےان لوگوں پر رشک آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لکھنے میں انھیں کیف و سرور حاصل ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر میں ترغیب کا انتظار کروں تو کچھ بھی نہیں لکھ سکتا۔ مجھے خود کی شدت سے تادیب کرنی پڑتی ہے۔ میں 4-5 بجے کے درمیان اُٹھ جاتا۔ کپ میں خود کے لیے جن سنگ (Ginseng): ایک جڑی بوٹی جس کا استعمال مختلف ادویات بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، کا ایک کپ تیار کرتا اور اپنے نوٹس لے کر بیٹھ جاتا، اپنے مواد کو منظم کرتا۔ ٹیک کی لکڑی کے فرنیچر سے آراستہ یہ خوب صورت کمرہ مجھے مطالعہ کے لیے میرے والد نے دیا تھا۔ اس میں ایک منقش ایرانی قالین اور آتش دان ہے۔ اس کمرے سے ملحقہ حصے میں یَوونی (Yvonne) میرے چچازاد بھائی کلبیر (Kulbeer) کے ساتھ بیٹھتا۔ (یوونی اخیر تک اسے کلَبر کہتا رہا) وہ میرے والد کے سکریٹری کے فرائض انجام دیتا تھا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ جب تک میری میز پر رکھے ہوئے سارے سادہ کاغذ بھر نہیں جائیں گے، میں اپنی کرسی سے نہیں اٹھوں گا۔ اکثرو بیشتر یہی ہوتا کہ میں جو کچھ لکھتا اسے پڑھ پانا دشوار ہوتا تھا۔ اسے میں ٹائپ کراتا اور پھر دوبارہ لکھتا۔ کبھی کبھی میں ایک ہی سطر کو پانچ یا چھے بار لکھتا جب تک کہ وہ پڑھنے کے قابل نہیں ہوجاتی۔ پھر میں کام روک کر کافی پیتا۔ کچھ دن چڑھنے پر کافی پینا میرے والدین کے گھر کا معمول تھا۔ اس تقریب کی صدارت میری والدہ کرتیں اور ہر ایک کے سامنے کافی، کریم اور شکر پیش کرتیں۔ کئی ایک مہمان بھی ہمارے ساتھ کافی پینے کے لیے آجاتے۔
میرے قارئین ان حالات سے واقف ہیں جنھوں نے مجھے شعبہ قانون سے ہٹاکر فورن سروس میں اور اس کے بعد رابطۂ عامہ نیز درس و تدریس اور بالآخر صحافت اور تصنیف کی جانب مہمیز کیا۔ یہاں ان مصنفوں کا ذکر بھی ناگزیر ہے جن سے میری شناسائی رہی، جنھوں نے مجھے متاثر کیا، اور اس کا بھی کہ مصنف بننے کے لیے کیا مسائل درپیش ہوتے ہیں، کیا تصنیف کوئی تفریحی شے ہے یا اس کے دم پر زندگی بھی بسر کی جاسکتی ہے؟
اسکول اور کالج میں میری خراب کارکردگی کے باوجود بچپن سے ہی مجھے ادیب بننے کی خواہش تھی۔ جونیئر اسکول کے زمانے میں ہی میں نے ایک ناول لکھنے کے لیے ایک کاپی خریدی تھی جس کے پہلے صفحے پر میں نے جلی حروف میں ناول کا عنوان درج کیا تھا: شیلاازخوشونت سنگھ۔ ان دنوںسیدھے سادے Sheilla نام کی بہ نسبت، جس میں صرف ایک ‘L’ ہوتا تھا، مجھے نام کچھ زیادہ ہی ماڈرن لگتا تھا۔ وہ کھلاڑی لڑکیاں مجھے مسحور کرتی تھیں جو بالوں کی دو چُٹیا لال پھیتوں سے باندھتیں، ہاف پینٹ پہنتیں اور لڑکوں سے ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھیں۔ میں کاپی لیے کئی دنوں تک اپنی ہیروئن کو تلاش کرتا رہا،میں نے شاید کچھ سطریں بھی لکھیں، لیکن SHEILLA کبھی مکمل نہیں ہوئی۔
برطانیہ میں کالج کے پانچ برس اوربالخصوص Inns of Court کی تعلیم کے دوران میری لکھنے کی خواہش نے قدرے زیادہ ٹھوس شکل اختیار کی۔ میں قانون کی کتابوں سے بیزار تھا اور افسانے یا شاعری پڑھ کر میں محظوظ ہوتا تھا۔ خوش نصیبی یہ رہی کہ جو کچھ میں نے ہندستان میں پڑھا تھا اس کا ایک بڑا حصہ میرے حافظے میں محفوظ رہ گیا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی شدید احساس تھا کہ شاعری اگر شاعر کی داخلی دنیا کا اظہار ہے تو نثر لکھنے کے لیے وسیع مطالعے اور اس سے بھی کچھ زیادہ نثر لکھنے کے لیے ذخیرۂ الفاظ پر قدرت ضروری ہے۔ میں ہمیشہ اپنے ساتھ لغت رکھتا اور جو لفظ سمجھ سے پرے ہوتے انھیں نشان زد کرلیتا۔ میں نے بائبل دوبارہ پڑھی جس سے میرا تعارف سینٹ اسٹیفنس کالج (دہلی) ہی میں ہوچکا تھا۔ (انجیل مقدس کا) عہدنامہ جدید مجھے قدرے خشک معلوم ہوا جبکہ عہدنامہ قدیم کا متن شاعرانہ تھا۔ میں نے The Song of Solomon, The Psalms, Proverbs اور Book of Job بار بار پڑھی اور اس کے بعض حصے حفظ کرلیے جو آج تک میری یادداشت کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بڑی تعداد میں بکواس نظمیں، لطیفے، چو بَیتے، بچوں کے گیت، لیوس تیرل (Lewis Carroll) کی نظمیں، گلبرٹ (Gilbert) اور سلیوان (Sullivan) کے اوپیرا بھی پڑھے۔ اس طرح میں نے خود کو ایک دیہاتی پنجابی سے مڈل کلاس انگریز میں ڈھالنے کی سعی کی۔ میں The Times کی لفظی پہیلیوں (Crossword) پر بھی ہاتھ آزمائی کرنے لگا۔ مجھے یہ ماننے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے قیمتی گھنٹے اس پر ضائع کیے۔ میں نے جن ناول نگاروں کو پڑھا ان میں اولڈس ہکسلے (Aldous Huxley) اور سمر سیٹ موم (Somerset Maugham) نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا۔ میں یہ خواہش کرتا کہ ہکسلے کے یہاں جملوں کے الٹ پھیر، طنزیہ حاضر دماغی اور قاری کو اپنی گرفت میں رکھنے کی صلاحیت کوجوڑکرمیں بھی اپناایک اسلوب پیدا کرسکوں۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ مجھے لکھنے کی ترغیب عظیم اور بڑے مصنّفین سے زیادہ دوم درجے کے لکھنے والوں نے دی۔ بالخصوص وہ ہندستانی ادیب جن کی کتابیں برطانیہ اور امریکہ میں شائع ہوچکی تھیں۔ جب میں نے ملک راج آنند، راجہ راؤ اور آر-کے ناراین کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو مجھے لگا کہ جیسا وہ لکھتے ہیں ویسا تو میں بھی لکھ سکتا ہوں اور اگر ان کی کتابیں بیرون ملک شائع ہوسکتی ہیں تو میری کیوں نہیں؟ یہ اندازہ کچھ غلط بھی نہ تھا۔
انڈیا (اس وقت لندن) میں اپنی دوسری تقرری کے دوران لکھنے کا ’پیشہ‘ اختیار کرنے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کیا۔ ادیب بننے کی خواہش رکھنے والوں کی طرح میں نے بھی معروف خواتین اور مرد قلم کاروں سے دوستی کی کوشش کی، اپنے لیے ان سے ان کی کتابوں پر دستخط کرائے۔ فرانکوئی مارس (Francois Mauriac) سے ان کے ناولوں اور تصویروں پر اوٹوگراف لیے۔ مجھے آندرے گاید (Andre Gide) کا ان کی خاتون سکریٹری کے نام ایک دستخطی خط ملا، اور میں نے اسٹیفن اسپینڈر (Stephen Spender)، میری میکارتھی (Mary Mcarthy)، نارمن میلر (Norman Mailer)، کامپٹن میکنیزی (Compton Mackenzie)، ساکے ورل، (Sacheverell)، سِٹ ول (Sitwell)، ڈایلان ٹامس (Dylan Thomas)، روزا منڈلیمن (Rosamond Lehmann)، سیمویل بیکٹ (Samuel Beckett) اور بعض دوسرے لوگوں سے مصافحے کیے۔ قلم کاروں کی یہ بچکانہ پرستش اس وقت تک جاری رہی جب مجھے احساس ہوا کہ مصنّفین سے صرف دعا سلام سے ہی کوئی مصنف نہیں بن جاتا۔ لکھنا ایک نہایت ذاتی عمل ہوتا ہے جس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرسکتا سوائے آپ کی ذات کے۔ تصنیف کی دنیا میں ’گرو چیلا‘ اور پیر و مرشد کے سے تعلقات جیسا کوئی ادارہ نہیں ہوتا۔ قلم کار خود اپنے لیے رہنما ہوسکتا ہے بس۔
لندن وہی ہندستان میں سفارت خانے میں دوسری تقرری کے دوران میری History of the Sikhs کی اشاعت ہوئی اور گرو نانک جی کی جپ جی صاحب کا منظوم ترجمہ بھی شائع ہوا۔ میں جب دہلی واپس آیاتو ’منوماجرا‘ (Train to Pakistan) کا آدھا حصہ لکھ چکا تھا۔ بھوپال میں اسے مکمل کرنے میں مجھے پندرہ روز اور لگے۔ اس پورے واقعے کو پہلے کے باب میں درج کیا جاچکا ہے۔
اگلے دو برسوں میں آل انڈیا ریڈیو کے بین الاقوامی نشریات کے شعبے سے وابستہ رہتے ہوئے میں نیرد سی۔ چودھری (Nird. C. Chaudhry)، رُتھ جھب والا (Ruth Jhabvala) اور منوہر مُلگاؤنکر (Manohar Malgaonker) سے متعارف ہوا۔ جلد ہی یہ تینوں میرے قریبی دوست بن گئے۔ نیرد بابو کی خودنوشت Autobiography of an Unknown Indian (ص 195) ابھی حال میں شائع ہوئی تھی۔ چوں کہ اس کا انتساب بھی برطانوی سامراج کے نام تھا، اور ہندستان میں جو کچھ بہتری آئی تھی اسے انھوں نے برطانوی سامراج سے ہی جوڑکر دیکھا تھا، اس لیے حکومت ہند کے سرکاری ا ور بیوروکریٹ حلقوں میں اس پر کچھ ہنگامہ بھی مچا۔ ان کی انگریزی زبان کی مہارت بنگال کے گاؤں کے بیان اور ملک کے مسائل پر ان کے تجزیاتی نقطۂ نظر پر میں فریفتہ ہوگیا تھا۔ میں نے ان سے اس وقت دوستی کی جب انھیں برادری سے باہر کیا جاچکا تھا۔ ان کو دوستوں کی ضرورت تھی اور انھوں نے میرا دوستی کا ہاتھ قبول کیا۔
نیرد بابو نہایت ٹھگنے قد کے تھے، وہ ہمیشہ سوٹ بوٹ اور ٹائی میں ملبوس رہتے تھے اور ان کے سر پر انوکھی خاکی رنگ کی ٹوپی سے تھوڑی بڑی ہوتی۔ جوکر جیسے لگتے تھے۔ گھر سے باہر نکلتے تو گلی کے لونڈے ’جانی واکر، جانی واکر‘ گاتے ہوئے ان کے پیچھے لگ لیتے تھے۔ وہ بھی غصیل مزاج تھے۔ ایک دفعہ ان کے دفتر کے ساتھی نے جو ان کے ساتھ کمرے میں ہی بیٹھا تھا، انھیں انگریزوں کی چاپلوسی کا طعنہ دیا تو وہ آگ بگولہ ہو اٹھے اور چیخے: ’حرام زادے، اپنا یہ تبصرہ واپس لے، ورنہ میں تیری کھوپڑی توڑ دوں گا۔‘ اس نے بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کردیا۔ پھر تو نیرد بابو اس کی میز تک پہنچے اور کانچ کے پیپرویٹ سے اس پر وحشیانہ حملے کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ لہولہان ہوگیا۔ پھر دونوں شکایتیں درج کرانے کے لیے صدر شعبہ مہرا مسانی کے پاس گئے۔ بیچاری مہرا کیا کرسکتی تھیں، بچوں کی طرح لڑ پڑنے پر تنبیہ کی۔ چودھری کے لیے ان کے دل میں قدرے مروت تھی اور دیگر غیر متعصب اور ترقی یافتہ اور کھلے دماغ والے ہندستانیوں کی طرح وہ بھی ان کی ہمت اور ذہانت نیز ان کی صلاحیت کااعتراف کرتی تھیں۔ لیکن وزیر برائے اطلاعات و نشریات ’کیسکر‘ ایسے بالکل بھی نہ تھے۔ جب انھیں اس معاملے کی خبر ملی تو انھوں نے نیرد چودھری کو ملازمت سے برطرف کرنے کا حکم صادر کردیا اور یہ دھمکی بھی دی کہ جن اخبارات نے بھی نیرد کے مضامین شائع کیے انھیں Black List کردیا جائے گا۔ نیرد کی حالت خستہ ہوگئی۔ ان کی کوئی اور آمدنی تھی نہیں مگر کنبے کی ضرورتیں اپنی جگہ تھی۔ مہرا مسانی، رتھ جھبوالا، ان کے شوہر اور میرے جیسے بعض دوست ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ ہم نے طے کیا کہ انھیں اور ان کی اہلیہ کو اپنے اپنے گھر مدعو کریں گے۔ یہاں وہ بہت سے غیرملکی مداحوں سے ملے۔ ان کی ایک کتاب(The Autobiography of an Unknown Indian) نے ہی ان کو عرش تک پہنچا دیا تھا۔ میرے والد(سر) سوبھا سنگھ بھی ان کے مداحوں میں اس لیے شامل تھے کہ ان کی کتاب تو پڑھی نہیں تھی مگر ان کے بارے میں مجھ سے سنا تھا۔ نیرد جب بھی ہمارے گھر آتے، میرے والد انھیں اپنے باغیچے کی سیر کراتے جہاں انھوں نے گلاب کی دلکش اقسام لگا رکھی تھیں۔ برطانوی حکومت کی جانب سے خطاب و القاب پانے والوں کی کچھ زیادہ ہی قدر کرتے تھے اور میرے والد تو ’نایٹ‘،’سر‘ کا شاہی اعزاز جو غیرمعمولی خدمات کے اعتراف کے طور پر دیا جاتا ہے تھے۔ دوسری طرف میرے والد نے بھی یہ محسوس کرلیا کہ نیرد بابو اپنے انگریز دوستوں میں بے حد مقبول ہیں اور ہر پارٹی میں توجہ کا مرکز بھی وہی ہوتے تھے۔ ان کی آپس میں خوب نبھتی تھی۔
نیرد اشتعال انگیز بھی تھے۔ ایک دفعہ وہ جھبوالا کنبے کے ساتھ کھانے کی میز پر تشریف فرما تھے کہ انھوں نے رتھ جھبوالا کی ماں سے کہا کہ ہندستانی تو پارسیوں کو ہم وطن نہیں سمجھتے۔ جھبوالا کی ماں جن کے شوہر میرٹھ سازش مقدمے میں جیل میں رہ چکے تھے، (اور وہ پارسی تھے) اپنا آپا کھو ہی نہیں بیٹھیں بلکہ وہ پھٹ ہی پڑیں: ’تم برٹش حکومت کے تلوے چاٹنے والے ہو، تم نے ہماری وطن پرستی پر شبہ کرنے کی جرأت کیسے کی؟‘ وہ پارٹی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ نیرد مطمئن تھے اور اپنی بات پر قائم۔ نیرد بابو کے ساتھ مصیبت یہ تھی کہ میں جن لوگوں سے مل چکا ہوں ان سے کہیں زیادہ معلومات ان کو تھی۔ ان کا علم وسیع تھا۔ تاریخ، ادب، سائنس، قدرتی عوامل، کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ ایک دفعہ ہینری کووُم جانسن (Henry Droom Johnson) برٹش کونسل کے سربراہ کے گھر ایک پارٹی تھی۔ میں نے ہینری کی اہلیہ جین سے کہا کہ آج پوری صبح میں ایک تقریر سنتا رہا جو وِٹ گینسٹاین (Wittgensdein) نام کے کسی سائنس داں کے ہائیڈریا اسی چیز کے متعلق کسی تھیوری کے بارے میں تھی۔ میں نے بڑے طنطنے سے یہ دعوا کیا کہ ’مجھے نہیں لگتا کہ وٹ گینسٹاین (Wittgensdein) کے بارے میں یہاں موجود کسی شخص نے بھی کچھ سنا ہوگا۔‘ یہ وہم وگمان میں بھی نہ تھاکہ فلسفیوں کے حلقے میںوٹ گینسٹاین ایک لیجنڈ کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں نے بڑی ڈھٹائی سے یہ شرط لگائی کہ ’اس کمرے میں موجود لوگوں میں نیرد کو چھوڑ کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔‘ میری شرط قبول کرلی گئی۔
جین نے جب یہ بات اپنے مہمانوں کو بتائی جو عالم و فاضل اسکالر تھے، لیکن وٹ گینسٹاین کا نام کسی نے نہیں سنا تھا، مگر نیرد بابو اس کے نظریے پر کھل کر بات کرنے لگے۔ اس سے بھی زیادہ حیران کن حادثہ میرے گھر پر ہوا۔ میں نے آیس لینڈ کے نوبل انعام یافتہ سایلن پی (Sillanpie) کو اپنے گھر دعوت دی تھی اور بعض ہندستانی مصنّفین کو ان سے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ آیس لینڈ کے ادب پر نوبل انعام یافتہ ادیب کو اپنی تقریر پلاکر نیرد چودھری نے وہ شام اپنے نام کرلی۔
نیرد بابو بہت خبطی بھی تھے۔ اپنے چھت کے باغیچے میں انھوں نے کیکٹس کے پودے کی کئی قسمیں لگا رکھی تھیں جو طلوعِ آفتاب کے بعد گھنٹے دو گھنٹے کے لیے کھلتے تھے۔ یہ نظارہ دیکھنے کے لیے وہ بعض لوگوں کو اپنے فلیٹ پر بلاتے تھے جو دور دراز موری گیٹ کے پاس واقع تھا۔ گاڑیوں کی قطاریں شہر کی گلیوں میں آڑی ترچھی چلتی ہوئی یہ دلفریب نظارہ دیکھنے کے لیے وہاں پہنچتیں۔ چوں کہ کھانا ان کی اہلیہ کو پکانا ہوتا تھا، اس لیے، وہ شاذ و نادر ہی کسی کو کھانے کی دعوت دیتے تھے، اور جب دیتے تھے تو وہ تجربہ ناقابلِ فراموش ہوتا تھا۔ گھر پر وہ ہمیشہ بنگالی دھوتی کُرتے میں ہوتے تھے اور فرش پر پالتھی مار کر لکھنے پڑھنے کا کام کرتے تھے۔
نیرد بابو سے میری دوستی یک طرفہ تھی۔ وہ گرو تھے، میں ان کا سرنگوں شاگرد تھا۔ وہ جب بھی مجھ سے متفق نہیں ہوتے تو مجھے بیوقوف کہتے تھے۔ ان کی اہلیہ اکثر احتجاجاً کہتیں: ’اگر تمھارا یہی رویہ رہا تو اپنے اس اکیلے دوست سے بھی محروم ہوجاؤگے۔‘ میرا ان سے الگ ہونے کا کوئی ارادہ نہ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس بھی ایسی کوئی وجہ نہ تھی۔ ان کی بہت ساری کتابوں میں کسی اور ہندستانی مداح کے بجاے صرف میرا تذکرہ ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ ہندستان سے محبت کرتے تھے لیکن ہندستانیوں کو جھیل نہیں پاتے تھے۔ میکس مُولر (Max Muller) کی سوانح لکھنے کے لیے وہ جب انگلینڈ گئے تو پھر واپس نہیں آئے۔
رتھ سے میری شناسائی تب ہوئی جب میں آل انڈیا ریڈیو کی بین الاقوامی سروس میں انگریزی شعبے کا سربراہ تھا۔ میں نے ان کو بات چیت کے لیے مدعو کیا۔ وہ بے حد عمدہ اسکرپٹ لکھتی تھیں اور جو کچھ وہ ریکارڈ کرا دیتی تھیں اسے شاذ و نادر ہی دوہراتی تھیں۔ اسٹوڈیو میں جانے سے قبل جب وہ کچھ منٹوں کے لیے کافی پینے کے لیے میرے کمرے میں رکیں تو میں ان کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔
رتھ جھابوالا کے ناولوں کو اگر کوئی قاری ترتیب وار پڑھے تو اسے ہندستان اور ہندستانیوں سے ان کے ازالۂ التباس ہونے کا احساس ہوجائے گا۔ اس بیزاری کی تکمیل ان کے بہترین ناول Heat and Dust (1975) سے ہوتی ہے جس کو بُکر ایوارڈ ملا تھا۔ مجھے احساس ہوگیا کہ بس کچھ وقت کی ہی بات ہے جب نیرد چودھری کی طرح وہ بھی ہندستان چھوڑ کر یوروپ یا امریکہ میں جابسیں گی۔ جب تک ان کے یہ طے کرنے کا وقت آیا، ان کے بعض ناولوں کو مرچینٹ آئیوری (Merchent Ivory) ٹیم فلموں کا روپ دے چکی تھی۔ کچھ ناول اور بھی تھے جن پر بننے والی فلمیں سیٹ پر تھیں۔ ان کے فلم ساز نیویارک میں رہتے تھے اور اس لیے رُتھ نے نیویارک ہی کو چُنا۔ تب تک ان کے شوہر کو بھی اندازہ ہوچکا تھا کہ وہ وہاں بھی عمارتوں کے خاکے اور نقشے بنا سکتے تھے۔ دہلی کی بعض قدیم عمارتوں کے جو خاکے انھوں نے بنائے ان کو چشم زدن میں کامیابی ملی۔
رتھ نے میرا تعارف انیتا دیسائی سے کرایا جو ایک بڑے کاروباری کی —آدھی یہود، آدھی بنگالی— اہلیہ تھیں۔ وہ ایک دبلی پتلی، خوش شکل خاتون تھیں جن کے دو بچے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ رُتھ سے متاثر تھیں اور ان کی یہودیت انھیں رُتھ کے قریب لے آئی تھی۔ ان کی تصانیف میں یک گونہ مماثلت تھی اور انیتا کو بھی اپنے ہم وطن سے زیادہ مقبولیت بیرونی لوگوں سے ملی۔ ان کی ایک گرمی کسولی میں گزری۔ اسی سال جنگل میں ایک بھیانک آتش زنی کی وجہ سے پہاڑی کا ایک پورا حصہ جل گیا جو چیڑ کے آتش گیر درختوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کچھ گھر بھی جلے تھے۔ انیتا کے ناول Fire on the Mountain (1977) اسی تجربے کی تحریک سے لکھا گیا ہے۔ رتھ کی طرح انیتا کو بھی اپنی یہودی وراثت کا احساس تھا۔ ان کا ناول Baumgartner’s Bombay (1988) ایک یہود خاندان کے گرد ہی گھومتا ہے۔
آل انڈیا ریڈیو میں دو برس کی ملازمت کے دوران میں اس شخص کے ساتھ خط و کتابت کا حوصلہ پیدا کرسکا جسے آگے چل کر ہندستان کا ’جان ماسٹرس‘ کہا گیا۔ ماسٹرس کی طرح منوہر ملگاونکر (میک) بھی فوج کی نوکری کرچکے تھے۔ وہ ایک ماہر شکاری تھے اور غیرملکی مہمانوں کو باگھوں کے شکار پر لے جانے کے لیے سفر کرانے والی ایجنسیوں سے ٹھیکے لیتے تھے، لیکن جلد ہی وہ ان خوب صورت جانوروں کی ہلاکت سے بیزار ہو اٹھے اور انھوں نے یہ کام چھوڑ دیا۔ انھوں نے مجھے ایک افسانہ دکھایا جو اس بارے میں تھا کہ ایک تنومند، خوب صورت لیکن بیوقوف باگھ کی زندگی کیسے بچائی تھی جسے سڑک کے بیچ میں لوٹنے کی عادت تھی۔ وہ کسی بھی رایفل بردار شخص کا بہ آسانی نشانہ بن سکتا تھا لیکن میک نے اس کے قریب گولیاں داغ کر اسے متنبہ کردیا کہ انسان کہیں زیادہ خطرناک جانور ہے اور اس سے دوری بنی رہنی چاہیے۔ باگھ دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میں نے اس افسانے کو نشر کر دیا۔ اس کے بعد میک ملگاؤں کو کون روک سکتا تھا! ان کے قلم سے ناولوں کی ایک دھار بہہ چلی: تیز رفتار، اذیت پسند اور زبردست ڈرامائیت سے بھرپور۔ انگلینڈ اور امریکہ میں ان کے ناولوں کی خوب پذیرائی ہوئی۔ مہاراشٹر سے وابستگی کے سبب انھوں نے مراٹھا سورماؤں پر بھی کئی ایک تاریخی ناول لکھے۔ کتابوں کی قطار لگانے کے دوران میک کو معلوم ہوا کہ وہ تو سونے کی کان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پشتینی جائیداد میں، جو گُوا سے بہت دور نہ تھی، مینگنیز (Manganese) دھات ہونے کا پتا چلا۔ اب وہ ایک بڑے بنگلے میں جس کے ساتھ ایک طویل و عریض باغ بھی ہے اور ان کا نجی سویمنگ پول بھی ہے، ایک انگریز زمیندار کی طرح رہتے ہیں۔ کتابیں اور اخباروں کے لیے کالم لکھتے وقت وہ اسکاچ، فینی اور دوسری شرابیں نوش فرماتے ہیں۔
میں ابھی بھی زندگی کے اس دور میں تھا جہاں میرا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص بھی عمدہ لکھتا ہے اس سے جان پہچان ہونی ہی چاہیے۔ لہٰذا میں نے حد سے آگے بڑھ کر سستھی براتا (Sasthi Brata) سے دوستی کرلی۔ یہ ان کا اصل نام نہیں تھا بلکہ بنگالی برہمن نام ’بھٹاچاریہ‘ کا مخفف تھا۔ میں نے براتا کا سوانحی ناول Confessions of an Indian Woman-Eater (1971)بھی پڑھا جو انگلینڈ سے شائع ہوا تھا۔ یہ واضح طور پر شہوانی زبان میں لکھا ہوا تھا اور رنگ رلیاں منا رہے کیسونوواکے کارناموں کی داستان تھا۔ میں نے Illustrated Weekly of India میں اپنے کالم میں اس ناول کی ستائش کی۔ میں نے The Spectator اور The New Statesman جیسے معروف انگریزی رسالوں میں ان کے بعض مضامین بھی پڑھے جو بہت ہی آسان اور خوب صورت زبان میں لکھے گئے تھے۔ بعدمیںمجھے معلوم ہواکہ سستھی براتا The Statesman (کلکتہ اور دہلی) میں کام کرچکے تھے اور انھوں نے جن لڑکیوں کے بارے میں قلم طرازی کی تھی وہ دہلی کے کافی ہاؤس حلقوں میں مشہور تھیں اور ان کی شناخت آسان تھی۔ وہ ظاہر ہے کہ برتا کے Confessions سے نالاں تھیں۔ اُن دنوں وہ لندن میں مقیم تھے، کسی انجینئرنگ یا کیمکل فرم میں ملازم تھے اور شاید کسی انگریز لڑکی کے ساتھ شادی کرچکے یا ساتھ رہے تھے۔
سستھی براتا نے لندن سے فون کرکے مجھے مطلع کیا کہ وہ ہندستان آنے کے منصوبے بنارہے تھے اور اگر میں Illustrated Weekly میں ان سے کچھ مضامین لکھنے کے لیے کہوں تو ہندستان میں ان کے قیام کا خرچ نکل آئے گا۔ میں اس کے لیے فوراً تیار ہوگیا۔ انھوں نے مجھ سے تاج محل ہوٹل میں ایک کمرہ بک کرانے کے لیے کہا جو میں نے کردیا۔
سستھی تاج میں ہفتہ بھر سے زیادہ رُکے اور دوستوں کی جم کر خاطر تواضع کی۔ قیام کے آخری دن انھوں نے بِل پر محض اپنا نام درج کرکے یہ لکھ دیا کہ اسے Illustrated Weekly کے ایڈیٹر کو بھیج دیا جائے۔ میں نے ادائیگی سے انکار کردیا کیوں کہ سستھی نے مجھے کوئی مضمون لکھ کر نہیں دیا تھا اور میں نے کمرہ بھی Weekly کے نام سے نہیں، ان کے نام سے بک کرایا تھا۔ ہوٹل، سستھی اور میرے درمیان مہینوں تک تین طرفہ خط و کتابت چلی۔ آخرکار ہوٹل کی ڈائرکٹر کامیلیہ پنجابی نے اس بل کو ہی رد کردیا۔
کوئی سال بھر بعد سستھی دوبارہ ہندستان آئے۔ میں نے ان سے ملنے سے صاف انکار کردیا۔ وہ کچھ دن میرے بیٹے راہل کے پاس ٹھہرے، اس سے کچھ رقم اُدھار لی اور جہاں تک مجھے علم ہے، اسے کبھی واپس نہیں کیا۔
اس کے بعد برسوں سے سستھی برت کی کوئی کتاب یا مضمون میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ افسوس کا مقام اس لیے ہے کہ اس میں بے پناہ خلاقانہ صلاحیتیں تھیں۔
—————-
میں ہم عصر مصنّفین میں تو سب سے عمدہ تخلیق کار وی ایس نئیپال (V. S. Naipaul) کو سمجھتا ہوں۔ ان کا پہلا ناول A House for Mr Biswas (1961) میں نے پڑھا تھا۔ اگرچہ میں کسی ملک میں کبھی نہیں گیا، لیکن یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس ناول میں وہاں بسے ہندنژاد لوگوں کی زندگی کا ایک مستند بیان ہے۔ ان کے ناولوں میں یہ سبھی کردار جیتے جاگتے نظر آئے نیز ان کے مکالمے نہایت دل چسپ ہیں۔ انگریزی ادب کی دنیا میں نئیپال کو جب ابھرتے ہوئے ستارے کا درجہ دیے جانے کے کچھ عرصے بعد وہ اپنے آباواجدادکی دھرتی دیکھنے کے لیے ہندستان آئے، تو ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھیں۔ وہ ایک انگریز خاتون تھیں اور بہت ناراض لگ رہی تھیں۔ دہلی پہنچنے تک انھوں نے جو کچھ دیکھا تھا وہ اس سے بہت نالاں ہوچکے تھے۔ نئیپال کو اُمید تھی کہ ان کو ’ہندستان کا لعل‘ کہا جائے گا اور وہ اپنی اہلیہ کو یہ دکھا سکیں گے کہ ان کی اتنی تعریف و توصیف اپنے ملک میں نہیں ہوتی ہے۔ مگر اس وقت تک نئیپال کو محض Cognoscenti کے ایک محدود حلقے نے پڑھا تھا جس کی تعداد ہر جگہ بہت مختصر ہوتی ہے۔ میں ان کا گائیڈ تھا۔ ان کو میں اپنے دوستوں کے یہاں لے گیا جن میں شاذ و نادر ہی کسی نے ان کو پڑھا تھا۔ ان کی خودداری کو بحال کرنے کے لیے میں انھیں مقامی کتب خانوں میں ہی لے گیا تاکہ وہ دیکھیں کہ ان کے نالوں کی کتنی زیادہ مانگ تھی۔ میں انھیں سورج کنڈ لے گیا۔ فروری کا مہینہ ختم ہونے کو تھا اور دہلی کے اس قدیم شہر کے کھنڈروں سے لگی وادی پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ ہم نے تغلق آباد قلعہ کی بھاری بھرکم دیواروں کے سایے میں سینڈوِچ اور گرم کافی کا ناشتہ کیا۔ قریبی گاؤں کے بچے ہمیں دیکھنے کے لیے جمع ہوگئے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ناک بہہ رہی تھی اور گندی آنکھوں پر مکھیاں بھِنبھِنارہی تھیں۔ نئیپال نے سورج کنڈ کے حسین منظر کو سفرنامے An Area of Darkness (1964) میں محض چار الفاظ میں نپٹا دیا، لیکن ان گندے دیہاتی بچوں پر انھوں نے کافی تفصیل سے لکھا۔ کشمیر میں زعفران کے کھیتو ںکے بیان میں بھی انھوں نے یہی انداز اختیار کیا۔ موسمِ خزاں میں کھلے سوسن کا وہ محض سرسری تذکرہ کرنے لیکن پیٹ ہلکا کرنے کے لیے فرن اٹھا کر بیٹھنے والی کشمیری عورتوں کا چرچا وہ بطورِ خاص کرتے تھے۔نئیپال کی طرزِ تحریر سے اندازہ ہوتا ہے کہ گندگی اور گھنونی چیزیں ان کے حواس پر چھائی رہتی تھیں۔
مجھے کم از کم New York Times کے لٹریری ایڈیٹر کی جانب سے دوبار فون کال آئی کہ میں وی ایس نئیپال پر ایک مضمون لکھوں۔ انھیں یہ امید تھی کہ اس سال ادب کا نوبل انعام نئیپال (Naipaul) کو ہی دیا جائے گا۔ میں نے اپنا مضمون لکھا لیکن اس سال یہ انعام نئیپال کو نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے۔ ان دنوں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ انگریزی میں لکھنے والے کسی بھی کالے شخص کو یہ انعام کبھی نہیں دیا جائے گا۔ برطانوی حکومت نے انھیں Knight کا خطاب ضرور دیا تھا، لیکن یہ نوبل انعام نہ ملنے کی خلش کو پورا نہ کرسکا۔ نئیپال نے اپنے نام کے پہلے کبھی Sir لفظ کا استعمال نہیں کیا۔ انھیں جب یہ اندازہ ہوگیا کہ نوبل انعام ان کو ملنے سے رہا تو ان کی تحریروں کی عمدگی کم ہوتی چلی گئی۔
—————–
ایک کرسمس کے موقعے پر میرے امریکی ناشر، گروؤ پریس (Grove Press) کے بارنی روزیٹ (Barney Rosset نے مجھے بطور تحفہ گِنس برگ (Ginsberg) کی نظموں کی کتاب ‘The Howl’ بھیجی۔ مجھے ان کے پرجوش اندازِ بیان نے بے حد متاثر کیا اور میں نے شکریے کا خط لکھتے ہوئے شاعر کے بارے میں کچھ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کچھ مہینے بعد میں نیویارک میں اپنے دوست، کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جان ہیزرڈ (John Hazard) اور ان کی اہلیہ سوسن کے گھر پر ٹھہرا ہوا تھا۔ روزیٹ (Rosset) نے مجھے بھی گرین وچ ولیج کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانے پر مدعو کیا۔ وہیں میری ملاقات ایلن گنس برگ سے ہوئی۔
—————–
کسولی میں کچھ زیادہ قلم کار نہیں جاتے تھے۔ موسمِ گرما میں ہندی کے دو معروف ناول نویس اُپندر ناتھ اشک اور راجندر یادو نے، جو کلیان ہوٹل میں مقیم تھے، مجھے فون کیا۔ دونوں ہی مجھے ہندی ادب میں اپنے کارہائے نمایاں کے بارے میں بتلانے کے لیے بیتاب تھے۔ میں ان کے ناموں سے البتہ واقف تھا لیکن ان کی لکھی ہوئی تحریریں نہیں دیکھی تھیں۔ وہ اپنے بارے میں بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط سے کام لے رہے تھے۔ راجندر یادو بار بار اپنی اہلیہ منّو بھنڈاری کا حوالہ دے رہے تھے جو خود بھی ایک مصنف تھیں۔ ان کے ناول ’مہابھوج‘ نے ان کو بے حد شہرت دلائی تھی۔ یہ ایک بیسٹ سیلر ناول ثابت ہوا تھا اور اس پر فلم بھی بنی۔ کسی روز ناشتے کے دوران اشک نے میری اہلیہ کو بتلایا کہ وہ محض سات سال ہی کے تھے کہ انھیں احساس ہوگیا کہ ان کی تقدیر میں ’مہا لکھاری‘ بننا لکھا ہے۔ ان کے اندر قصہ گوئی کی صلاحیت غضب کی تھی اور اپنی پہلی بیوی سے نجات کے متمنی تھے، اس لیے، ان کے خلاف وہ بڑے مضحکہ خیز ظالمانہ انداز میں چھینٹا کشی کرتے تھے۔ اشک نے بہت سارے ناول لکھے تھے اور الٰہ آباد میں ان کا پبلشنگ ہاؤس بھی تھا۔ شہرت کے باوجود انھیں پیسوں کی تنگی ہمیشہ رہی۔ ایک بار تو انھوں نے یہ اعلان بھی کردیا تھا کہ وہ اب لکھنا بند کررہے ہیں کیوں اس سے کوئی رقم حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اب سے سبزیوں کی دکان لگائیں گے کیوں کہ ناول لکھنے سے آلو گوبھی بیچ کر کہیں زیادہ کمائی ہوتی ہے۔ اس پینترے کی وجہ سے ان کو خوب شہرت ملی۔
قلم کی دنیا میں انکساری ذرا دور کی کوڑی ہے۔ بالخصوص ہندستانی ادیبوں کے یہاں جن میں یوروپ والوں کے مقابلے آداب و تکلفات ذرا کم ہیں، خود ستائی کوئی قبیح فعل نہیں۔ علاقائی زبانوں کے ادیب اپنی خدمات کا بکھان کرنے میں ذرا بھی ہچکچاتے نہیں۔ اردو زبان کے عظیم ترین شاعر غالب فخریہ اعلان کرتے تھے کہ یوں تو درجنوں شاعر موجود ہیں پھر بھی میرا اندازِ بیان ان سب سے ممتاز ہے۔ آج کل کے ادیب اپنی سالگرہ کی دعوت دیتے ہیں، اپنی تعریف میں قصیدے پڑھواتے ہیں اور اپنے ’ابھی نندن گرنتھ‘ (Fest script) شائع کرکے تقسیم کراتے ہیں۔
انگریزی میں لکھنے والے بعض ہندستانی ادیب بھی باہمی ستائش سے نہیں چوکتے۔ چوں کہ اکثریت کتابیں پڑھنے والوں کی نہیں ہوتی، سیاست داں اور نوکرشاہ تو اس فہرست میں بالکل ہی شامل نہیں ہیں، اور چوں کہ عوام کی یادداشت محدود ہوتی ہے، اس لیے، اپنا بکھان کرنا ہی سب سے موثر حربہ ہے۔ بس ایک ناول All about Hatterer (1948) اور ایک چھوٹا سا ڈراما Hali لکھا تھا۔ یہ ناول بلاشبہ ایک عمدہ تحریر ہے، لیکن میں شاید ہی اس کا تصور کرسکتا ہوں کہ دیسائی جتنا کم لکھ کر لوگ نوبل انعام پانے کی خواہش بھی کرسکتے ہیں۔ لیکن دیسائی نے (جب وہ لندن میں پریس سے منسلک تھے) مجھے پھسلانے کی کوشش کی کہ میں ان کے نام کی سفارش انتخابی کمیٹی کے سامنے حکومتِ ہند کی جانب سے کروں۔ یہ معاملہ پھر ڈاکٹر رادھا کرشنن کے سامنے پہنچا جو اُس وقت ماسکو میں ہمارے سفیر تھے، انھوں نے مجھے خوب پلائی۔
ایک دفعہ تو دہلی کے تمام اخبارات میں صفحۂ اول پر یہ خبر شائع ہوئی کہ ہندی کے قلم کار وتساین (Vatsayan) کو جو اگییہ (Agyeya) کے قلمی نام سے لکھتے تھے، یہ اطلاع دی گئی ہے کہ اس سال کا نوبل انھیں ہی ملنے والا ہے۔ کچھ دنوں تک اخبارات میں یہی خبر شائع ہوتی رہی کہ دیکھیے ہندی کی کتنی بھاری عزت افزائی ہورہی ہے، اور ان کی اہلیہ کپلا واتسیاین کے انٹرویو شائع ہوتے رہے۔ چند دنوں کے بعد خبر موصول ہوئی کہ انعام تو اسرائیل کے قلم کار ایگنان (Agnan) کو دے دیا گیا ہے۔ یہ غلط خبر کیسے پھیلی، اس بارے میں پوچھے جانے پر واتساین میاں بیوی نے یہ بھونڈی سی صفائی دی کہ تار بابو نے Agnon کی جگہ غلطی سے Agyeya پڑھ لیا تھا۔ کس ڈاک خانہ کا کون سا تار بابو، کوئی نہیں جان سکا؟
اپنی تشہیر اور پروپیگنڈہ کرنے کی سب سے نمایاں مثال ڈاکٹر گوپال سنگھ دردی کی ہے۔ انھوں نے خود کے بارے میں جو من گھڑت کہانی پھیلائی اور اس سے جس طرح استفادہ کیا، اس کے بارے میں میں لکھ چکا ہوں۔
کچھ سال بعد خبریں موصول ہوئیں کہ ملیالم کی شاعرہ کملا داس (Kamla Das) کو اس انعام کا امیدوار تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ خبر بھی تمام اخبارات میں پہلے صفحہ پر شائع ہوئی۔ کملا کی ملیالی زبان میں بطور شاعرہ بہت ستائش ہوئی ہے اور انھوں نے خود اپنی زندگی پر ایک ناول بھی لکھا ہے جس میں انھوں نے اپنی شادی اور جنسی زندگی کی بے باک تصویر کشی کی ہے۔ کملا کے انتخاب کے بارے میں چھنے والی خبروں کا میں نے بھی جائزہ لیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ ان کے جیسی نیک خاتون بھی خود کی تشہیر کے موہ میں الجھ کر رہ گئی۔ نہایت برہم ہوکر انھوں نے مجھے فون کیا اور فون پر ہی چیخنے چلانے لگیں۔ ان کے بیٹے نے مجھے ایک قانونی نوٹس بھجواکر معذرت طلب کی، ورنہ ۔۔۔ لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔
مختلف رسائل، اخباروں کے ایڈیٹر اور ہندستان میں پینگوئن و ایکنگ (Penguin Viking) کے اعزازی ایڈیٹر کے روپ میں ذہین باحوصلہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں جو کچھ کرسکتا تھا وہ میں نے کیا ہے۔ ان میں سے جس کے اندر بھی کچھ قابلیت تھی وہ اس سے مستفید ہوئے۔ ان میں ایک تھے ایم جے اکبر جو کلکتہ کے The Telegraph کے ایڈیٹر بنے، پھر پارلیمنٹ کے ممبر بنے، اور سیاسی و سماجی معاملات پر متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ باچی کارکریا (Bachi Karkarea) جن کو میں نے بامبے ڈائنگ کے واڈیا گھرانے پر اپنی کتاب کے لیے منتخب کیا۔ (واڈیا خاندان کو متن پسند نہیں آیا اور اس کے سبب کتاب شائع نہیں ہوئی) میں نے ان کا نام ہوٹل مالک ایم ایس اوبیراے کی سوانح کے لیے بھی پیش کیا اور اس کتاب کو پینگوئن وایکنگ نے شائع کیا۔ رسالوں، ریڈیو اور ٹی وی کے لیے کتابوں پر تبصرے کرنے کے دوران میں بہت سے نئے قلم کاروں کو آگے بڑھانے میں کامیاب رہا۔ ان میں امیتاؤ گھوش (Aitav Ghosh)، اُپ منیو چٹرجی (Upamanyu Chatterjee)، گیتا ہری ہرن (Geeta Hariharan)، شمع پھٹہلّی (Shama Puttenahalli)، ایلن سِیلی (Allan Sealy)، رُکن اڈوانی (Rukun Advani)، رمیش مینن (Ramesh Menon)، مُکل کیشون (Mukul Kesvan) اور سب سے بڑھ کر وکرم سیٹھ کے نام شامل ہیں۔ The Golden Gate پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے لکھا تھا کہ ہندستان میں بالآخر بین الاقوامی سطحِ تخلیق میسر آگیا جو اپنے ملک کا نام روشن کرے گا۔ ان کے ناول A Suitable Boy کی کامیابی سے یہ بات ثابت ہوچکی ہے کہ میری پیش گوئی غلط نہیں تھی۔
نوجوان امیدواروں کی حوصلہ افزائی کے اپنے ہی جوکھم ہوتے ہیں جنھیں ادب کی دنیا میں لانے سے مہلک نتائج برآمد ہوئے۔ ان میں ایک نام اندرانی ایکٹھ گیالت سین (Indrani Aikath Gyaltsen) کا ہے۔ وہ بہار میں رہنے والی ایک بنگالی لڑکی تھی جس نے دارجلنگ کے پاس چائے کے ایک باغ کے تبتی مالک سے شادی کی تھی۔ ہمارا تعارف گلین برن (Glen Burn) چاے باغ میں اس کے ساتھ ٹھہرے ہوئے جرمن سفیر کی بیوی نے کرایا تھا۔ پھر ہم خط و کتابت کرنے لگے۔ اس نے مجھے اپنی کچھ نظمیں بھیجیں۔ میں نے صدق دلی سے اقرار کیا کہ شاعری کے بارے میں میری معلومات بہت کم ہیں لیکن اگر وہ کوئی ناول یا پھر افسانے لکھے تو میں شاید کچھ مدد کرسکوں گا۔ اس نے اپنے خرچ پر اپنی نظمیں شائع کرائیں اور ان کا انتساب میرے نام کیا۔ میں اس لیے نثر لکھنے کے لیے زور دینے لگا۔ اس نے اپنے ناول Daughters of the House (1991) کے باب مجھے بھیجنے شروع کردیے۔ پینگوئن وایکنگ میں میرے رفیق کار ڈیوڈ دیویدار نے ان کو قبول کرکے برطانیہ اور امریکہ کے ناشرین کے ہاتھوں فروخت کردیا۔ اندرانی کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوچکا تھا۔ لیکن وہ کامیابی اور بہت جلد شہرت کی تمنا کرنے لگی۔ ایک بار جب وہ کلکتہ کتاب میلے میں میرے ساتھ تھی، مجھ سے پوچھ بیٹھی: ’مجھ سے کوئی میرا آٹوگراف کیوں نہیں مانگتا؟‘ میں نے اسے یقین دلایا کہ وہ کچھ اور ناول لکھ لے گی تو لوگ بھی اس سے آٹوگراف مانگیں گے۔ کتاب میلہ کے آخری کچھ دنوں کے دوران اس کا دوسرا ناول Cranes Morning (1993) سامنے آیا۔ (اس کا انتساب بھی میرے ہی نام تھا) ہندستان میں اس پر اچھے تبصرے ہوئے اور بیرونی ناشرین نے اسے قبول کیا، لیکن یہ اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ لوگ اسے تسلیم کریں، اس کے بارے میں بات کریں۔ اسے کلکتہ کے The Statesman میں لکھنے کے لیے ایک ہفتہ وار کالم دیا گیا۔ اس نے جوش و خروش سے لکھنا شروع کردیا کیوں کہ اس کے زیادہ تر دوست یہی اخبار پڑھتے تھے۔ میں نے اسے ایک سے زیادہ دفعہ آگاہ کا کہ جو کچھ ذہن میں آجائے اسے نذرقلم کرنے سے بات نہیں بنتی۔ کچھ مہینوں کے بعد The Statesman نے اس کے کالم چھاپنے بند کردیے۔ اس بات سے اس کو سخت صدمہ پہنچا۔ ساتھ ہی اس کے خاندان کے افراد سے تعلقات تلخ ہونے لگے۔ وہ دارجلنگ چھوڑ کر چائی باسا (Chaibasa) (بہار) میں اپنے بیمار والد کے پاس آگئی۔ وہ لقوے کے سبب مفلوج ہوچکے تھے۔ جب ان کی وفات ہوئی، وہ والد کے قریب ہی تھی۔ ماں اور بہن سے اس کی کبھی نہیں نبھی۔ چائے باسا میں اس کے والد کی کھدان اور مکان کو لے کر ان کے درمیان تنازع تھا، لیکن اس سے بھی سنجیدہ کوئی بات اسے اندر اندر کھائے جارہی تھی۔ میرے نام اس کے خط مختصر، اور مختصر ہونے لگے اور اس نے بے حد آزردگی سے شکایت کی۔ پینگوئن وایکنگ نے اس کا تیسرا ناول قبول کرلیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی وہ رنج و الم کے اس ماحول سے بار نہ پاسکی۔ عجیب سا اتفاق یہ ہوا کہ اس کے تیسرے ناول کا عنوان Hold My Hand I am Dying تھا۔ ایک صبح وہ بستر پر بے ہوش پائی گئی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ کلکتہ سے اس کے شوہر کو بلایا گیا۔ اگلے روز اس کی وفات ہوگئی کہ اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہ تھا۔
وفات سے ایک روز پہلے اندرانی نے مجھے ایک چھوٹا سا خط لکھا تھا۔ یہ مجھے دو دن بعد ملا۔ اس سے اشارہ ملتا تھا کہ کچھ تھا جو اسے پریشان کررہا تھا۔ میرے پاس یہ ماننے کا سبب نہ تھا کہ اس نے خود کی جان لی تھی۔ جب سب کچھ اس کی پسند کے مطابق ہورہا تھا تو وہ اپنا کیریئر کیوں ختم کرتی؟
اس کا ایک ممکنہ جواب مگرکچھ ماہ بعد ملا جب پینگوئن وایکنگ کو ایک قانونی نوٹس ملا کہ Crones Morning کے بعض حصے بیس سال پہلے شائع ہوچکے ایک امریکی ناول سے سرقہ کیے گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکی ناشر کی توجہ اس طرف مبذول ہو، اس سے پہلے اندرانی کو قارئین کے خط ملے ہوں گے جن میں اس پر سرقے کا الزام لگایا گیا تھا۔ اندرانی کو لگا ہوگا کہ محض اب کچھ وقت کی بات ہے جب یہ سرقہ اس کے منہ پر دے مارا جائے گا اور اس کا ایک مشہور ادیب بننے کا خواب ریزہ ریزہ ہوکر بکھر جائے گا۔ میں نے دونوں ناولوں کے متعلقہ حصوں کاموازنہ کیا۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس نے دوسرے ناول سے کچھ حصے ذرا سے پھیر بدل کے ساتھ اڑا لیے تھے۔ یہ بات بھی واضح تھی کہ اس کے لیے ایسا کرنا اس لیے قطعی ضروری نہ تھا کہ زبان پر اسے اتنی ہی قدرت حاصل تھی جتنی کسی بھی اچھے لکھنے والے کو ہوسکتی ہے۔ یہ تو ناول کو آگے بڑھانے اور پورا کرنے کی جلد بازی اور بے صبری تھی جو اس نے ایسا بیوقوفی بھرا قدم اٹھایا۔ میں اسے بہت پسند کرنے لگا تھا اور اس لیے اس پر دباؤ ڈالنے کے لیے میں خود کو معاف نہیں کرسکتا۔ وہ میری سرپرستی میں تھی، میری بیٹی اور میری پسندیدہ لڑکی بھی تھی۔ میرے مطالعے کے کمرے میں اس کی تصویر ایک فریم میں آویزاں ہے۔
—————–
ادیب بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ پہلا، جنون۔ دولت کی ریل پیل اس کی متحرک نہیں ہوسکتی۔ (ہوٹل، پان کی دکان، گیس ڈِپو، قانون یا دوا علاج کے پیشے میں اس سے کہیں زیادہ کمائی ممکن ہے) نہ ہی نام اور شہرت کی طلب اس کی محرک ہے، وہ تو سیاست یا فلموں میں کہیں زیادہ آسانی سے مل سکتی ہے۔ درحقیقت بہت سے ادیبوں کے لیے یہی بات واضح نہیں ہے کہ انھوں نے قلم ہاتھ میں کیوں لیا، بس وہ اتنا ہی کہتے ہیں کہ کوئی اندرونی ترغیب ہے جس نے ان کو مجبور کیا۔ زیادہ تر صورتوں میں جب انھیں معلوم ہوتا کہ واقعی ایک مصنف بننے کے لیے خواہش کے علاوہ بھی بہت کچھ درکار ہے تو ان کی تحریک ختم ہوجاتی ہے۔ یہ خواہش بار بار اٹھتی ہے۔ کچھ لوگ چھوٹے چھوٹے مضامین، ادھورے افسانے یا ناول لکھ کر ایک راستہ نکالنے کی سعی کرتے ہیں اور پھر ہار مان لیتے ہیں، یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے اندر مصنف بننے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ زیادہ تر حساس لوگوں میں شاعری کا ایک ذخیرہ موجود ہوتا ہے جو عنوانِ شباب میں جلا پاکر لفظوں کی صورت اختیار کرتا ہے۔ بعد میں یہ خواہش مرجاتی ہے۔ نثر لکھنا کہیں زیادہ مشکل ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے تمام کلاسکی اور جدید ادب پڑھا ہو، آپ کے پاس الفاظ کا شاندار ذخیرہ موجود ہو اور سب سے بڑھ کر آپ میں یہ قوت ہو کہ کام پورا ہونے تک آپ ہار نہ مانیں۔ مختصر یہ کہ آپ میں استقلال ہو، کورے کاغذ کو تکتے ہوئے گھنٹوں بیٹھے رہیں اور جب تک وہ بھر نہ جائے، آپ ڈٹے رہیں۔ کاغذ پر جو کچھ بھی درج ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس میں بہت سی بکواس باتیں بھی ہوں، لیکن یہ ثابت قدمی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ جلد یا بدیر آپ کی تحریر میں بہتری آئے گی، آپ میں جو مصنف چھپا بیٹھا ہے وہ باہر آئے گا۔ دوستوں کے نام لمبے لمبے خط لکھنے سے عمدہ مشق ہوتی ہے۔ میری راے میں روزانہ ڈائری لکھنا بھی کارآمد ہوسکتا ہے۔ اخبارات میں باقاعدگی سے کالم لکھنا اور وقت کی پابندی کرنا ایک نیک عمل ہوتا ہے۔ اس میں کچھ دنوں کے لیے بھی رخنہ پڑے تو پھر اسے لَے میں لانا مشکل ہوجاتا ہے۔
مجھے لکھ کر کیا ملا ہے؟ جو اخبارات اور رسائل میرے کالم چھاپتے ہیں ان سے ڈھیر ساری رقم ملی ہے۔ اتنا تو مجھے اپنی کتابوں سے نہیں ملا، لیکن ان دو ذرائع سے آنے والی آمدنی نے مجھے ٹیکس ادا کرنے والوں کی پہلی قطار میں لاکھڑا کیا ہے۔ میرا مسئلہ آمدنی کا نہیں، ٹیکس ادا کرنے والوں میں شامل ہونے کا ہے۔ آمدنی سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ مجھے پڑھتے ہیں اور میں ہندستان میں کہیں بھی رہوں، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی ستائش سے کسی کا دماغ بھی پھر سکتا ہے۔ لیکن دولت اور شہرت سے بڑھ کر مجھے اپنی تحریروں سے خود کی تکمیل کا احساس ہوتا ہے۔ یہ احساس مجھے قانون، سفارت یا درس و تدریس کے پیشوں سے حاصل نہیں ہوا، لیکن جب میں ہر روز قلم چلاتا ہوں تو یہ مجھے بھرپور مقدار میں حاصل ہوتا ہے۔ جب تک قلم میرے ہاتھ سے نیچے نہ گرے، میں یہی کرتے رہنا چاہتا ہوں۔
حواشی
1 خوشونت سنگھ کی خودنوشت سوانح’Truth Love and Little Malice’ کے باب on writing and writersکے منتخب حصوں کا ترجمہ
Dr. Javed Alam
Azampur Dehpa, Pilkhuwa,
Hapur, (U.P)
Pin – 245304
Mob.: 9717984657
Email: Javed.alam075@gmail.com